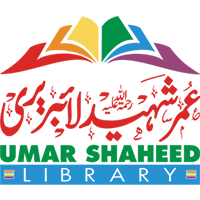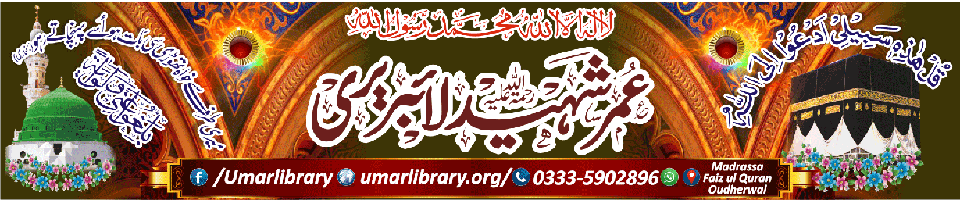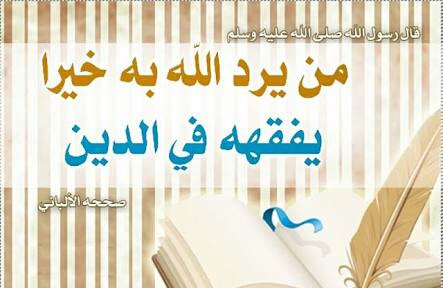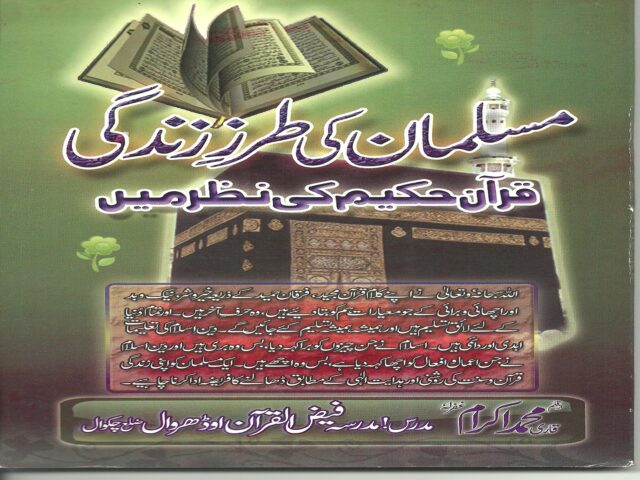حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب ’’حلال وحرام‘‘ سے ماخوذ
دنیا کے بعض مذاہب نے نکاح کو ایسا اٹوٹ رشتہ بنادیا ہے کہ نفرت کی بنیادوں پر بھی اس کی کھوکھلی دیوار کو قائم رکھنا ضروری ہے، مغرب کی جدید ترین تہذیب میں نکاح محض خواہش نفس کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے نہ اس کے ساتھ تو الد و تناسل کا جذبہ ہے اور نہ پائیدار محبت و سکون کی دنیا اور نہ رشتہ نکاح کے ساتھ عفت و عصمت کی برقراری۔ اگر جاہلیت کے ان جدید و قدیم بتکدوں کا جائزہ لیاجائے اور ان کے چہروں سے تہذیب و ثقافت کی مصنوعی قلعی کو کھرچ کردیکھا جائے اور ان کا اسلام کی فطری ،معتدل اور متوازن تعلیمات سے تقابل کیاجائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی وہ نظام حیات ہے کہ جس نے متوازن اصولوں اور بہترین مقاصد پر احکام نکاح کی بنیادرکھی ہے اور ہر جگہ افراط و تفریط سے دامن بچائے رکھا ہے۔
منگیتر کو دیکھنا
شریعت اسلامی چاہتی ہے کہ رشتۂ نکاح ایک پائیدار رشتہ ہو، اس لئے وہ ابتدائً ہی ناپائیداری کے تمام دروازوں کو بند کردیتی ہے اسی لئے اس لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی بلکہ آپﷺ نے اس کی ترغیب فرمائی کہ جس کو نکاح کا پیام دیا جائے، پہلے اس کو دیکھ لیا جائے۔
’’جب تم میں سے کوئی کسی خاتون کے یہاں نکاح کا پیام بھیجے تو جو چیز اس کے نکاح کی داعی بنی ہے اس کو دیکھ سکے تو دیکھ لے۔‘‘ (ابوداؤد:۲/۲۸۴)
یہ بھی ضروری نہیں کہ لڑکی اور اس کے اولیاء سے پیشگی اجازت لے لے بلکہ غیر محسوس طور پر دیکھ لے تو یہ بھی کافی ہے۔ حضرت جابرؓ کی مذکورہ روایت میں خود اس امر کی صراحت ہے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیام دیااور چھپ کر اسے دیکھا۔ اجازت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُمّ کلثوم صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اجازت ہی سے دیکھا تھا۔ تاہم خیال ہوتا ہے کہ بلااظہار دیکھنا زیادہ مناسب ہے کہ لڑکی کو دیکھ کر پھر رشتہ رد کر دیاجائے تو اس کا نفسیاتی اثر اچھا نہیں ہوتا، لڑکا خود دیکھنے کے بجائے گھر کی دوسری عورتوں کے ذریعہ لڑکی دکھلوائے او ان کی خبر پر اعتماد کر ے تو یہ بھی کافی ہے۔ویسے جیسا کہ مذکورہوا لڑکا خود بھی لڑکی دیکھ سکتا ہے۔ ہندوستان میں لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔
منگیتر کا ہاتھ اور چہرہ ہی دیکھ سکتا ہے(حاشیہ ابوداؤد۲/۲۸۴مطبوعہ دہلی) اور کپڑے کے اوپر سے جسم کا مجموعی قد وقامت اور بس۔ عورتیں دیکھیں تو شریعت کے عام اصول وقواعد کے مطابق ،ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ چھوڑ کر جسم کے بقیہ حصے حسب ضرورت دیکھ سکتی ہیں۔ (رد المحتار: ۵/۲۳۷باب الحظر والاباحۃ) البتہ لڑکے کے لئے ضروری ہے کہ نکاح کے ارادہ سے دیکھے، بدنظری مقصود نہ ہو۔ اگر نکاح کے ارادہ سے دیکھے تو گوشہوت کا اندیشہ ہو پھر بھی دیکھنا جائز ہے(المغنی:۷/۷۴)یہ ایک شرعی ضرورت ہے… مغربی تہذیب کی اباحیت نے یہ نعرہ بھی لگایا ہے کہ زوجین کو عقد سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ایک عرصہ تک وقت بھی گزارنا چاہئے اور باہم محبت اور پیارکے تعلقات رکھنے چاہئیں، لیکن اسلام اس طرح کے بے حیائی کے عمل کو حرام اور گناہ عظیم تصور کرتا ہے… اسلام کا نقطۂ نظریہ ہے کہ ایک اجنبی مردو عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ تخلیہ میں ملنا جائز نہیں(مشکوۃ المصابیح،کتاب النکاح) اس لئے کہ ایسا کرنا ایک عورت کے ساتھ کھلی زیادتی اور ظلم ہے کیونکہ اس تجربہ نے اگر صنفی تعلقات کے تجربہ تک پہنچادیا اورپھررشتہ نہ ہو سکا تو اس کا خمیازہ تنہا عورت ہی کو بھگتنا پڑے گا۔
پیام پر پیام
پیغام نکاح دینے میں آپﷺ نے اس بات کی بھی ہدایت فرمائی کہ اگر ایک شخص کسی لڑکی کو پیام دے چکا ہو تو اب تم اپنی طرف سے پیام نہ دو۔’’ولا یخطب بعضکم علی خطبۃ اخیہ‘‘(بخاری:۲/۷۷۳) کہ اس سے باہم منافست، رقابت اور نفرت پیدا ہوتی ہے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اس پیام میں لوگ دلچسپی لینے لگیں، اگر لڑکی کی طرف سے اس پیشکش کو رد کردیاجائے یا اس کی طرف کوئی میلان ورحجان نہ ہوتو پیام دے سکتے ہیں۔ رشتہ کی پیشکش گو لڑکے اور لڑکی کسی طرف سے بھی ہوسکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ لڑکے کی طرف سے ہو۔ اکثر ازواج مطہراتؓ کے لئے آپﷺ نے خود نکاح کی پیش کش کی تھی، صحابہؓ کا عمل بالعموم اسی پر تھا۔ گو ایک آدھ مثال اس کے خلاف بھی ملتی ہے، اس لئے کہ لڑکی کی طرف سے نکاح کی پیش کش بظاہر حیا کے خلاف محسوس ہوتی ہے اور مردوں کی طرف سے بیوی کی تلاش اس کی قوامیت اور ازدواجی زندگی میں اس کی ایک گونہ برتری کے عین مطابق ہے۔
انتخاب رشتہ کا معیار
مردوعورت اور اولیاء رشتہ کے انتخاب و ترجیح میں کس معیار کو ملحوظ رکھیں؟ آپﷺ نے اس کو بھی واضح فرمادیا ہے۔ آپﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسے رشتے آجائیں جن کی دینی واخلاقی حالت سے تم مطمئن ہو۔’’من ترضون دینہ وخلقہ‘‘(ترمذی،کتاب النکاح:۱/۲۰۷) تو قبول کر لو کہ ایسا نہ کروگے تو فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عورتوں سے چاروجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ ا)مال(۲)حسب وخاندان(۳) جمال(۴)اور دین، ان میں دیندار سے شادی کر کے ازدواجی زندگی کی کامیابی حاصل کرو۔(ترمذی عن ابی ہریرۃؓ: ۱/۲۰۷)
پس گو نکاح میں خوبصورتی اور طبیعت کے مطابق کسی او ر مرغوب و صف کو بھی معیار بنایا جا سکتا ہے جس کی طرف قرآن نے(ماطاب لکم من النسائ)’’جو عورت تجھے پسند ہو‘‘ کے لفظ سے اشارہ کیا ہے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی دینداری اور اخلاق ہی کو معیار بنایا جائے،علامہ کاسانیؒ کا بیان ہے: ’’وعندنا الافضل اعتبار الدین والاقتصار علیہ‘‘
ہمارے نزدیک دین کا اعتبار اور صرف اسی پر اکتفاء کرنا افضل ہے۔(بدائع الصنائع:۲/۳۱۷)
کفاء ت
رسول اللہﷺ کی بعض روایات میں نکاح میں کفاء ت یعنی برابری اور ہمسری کا لحاظ کرنے کو کہا گیا ہے، عام طور پر اس سلسلہ میں جو حدیثیں نقل کی جاتی ہیں وہ ضعیف اور نامعتبر ہیں۔ تاہم فقہاء نے مجموعی طور پرنو(۹)امور میں کفاء ت کا اعتبار کیا ہے۔
۱)نسب وخاندان (۲)آزادی وغلامی (۳)خاندانی مسلمان یا نو مسلم ہونا (۴)دیانت وتقویٰ (۵)مال اور معاشی سطح (۶)حسب (۷)پیشہ وذریعہ معاش(۸)جسمانی عیوب سے محفوظ ہونا(۹)اورعقل وفہم… لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں جو چیز قابل توجہ ہے وہ محض دین و اخلاق ہے۔ خاندان اور برادری کے لحاظ میں غلو اسلام کی شان مساوات اور مذاق اُخوت کے خلاف ہے۔ آپﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے تم سے جاہلیت کا امتیاز اور آباء واجداد پر فخر کو ختم کردیا ہے، انسان یا تو مؤمن تقی ہے یا فاجرشقی۔ (ابو داؤد ،باب التفاخر بالانساب)
(جاری ہے)
الفقہ
حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب ’’حلال وحرام‘‘ سے ماخوذ
(شمارہ 472)
رسول اللہﷺ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خود اپنے عمل کے ذریعہ اس کی مثال پیش فرمائی، آپﷺ نے اپنی چچازاد بہن حضرت زینبؓ کا نکاح اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ انہی حضرت زیدؓ کے لڑکے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپﷺ نے فاطمہ بنت قیسؓ سے فرمایا جو قریشی خاتون تھیں۔ حضرت ضباعہ بنت زہیر بن عبدالمطلب کا نکاح مقداد بن اسودؓ سے فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ مقداد اور زید کا نکاح ہم نے اس طرح اس لئے کیا ہے کہ اخلاق شرافت کا معیار بن جائے’’ لیکون اشرفکم عند اللّٰہ احسنکم خلقا‘‘(بیہقی:۷/۱۳۵) آپﷺ کی اور آپﷺ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیات میں اس طرح کی مثالیں کثرت سے موجود ہیں۔اس لئے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، رہن سہن، دین ، حالت، دیانت اور اخلاق یہی چیزیں ہیں جو رشتہ کے انتخاب کے وقت ملحوظ رکھے جانے کے لائق ہیں، یوں انسانی طبیعتوں کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے خاندان ،ذریعۂ معاش، معاشی سطح اور اسلام میں قدامت وجدت وغیرہ کو بھی ملحوظ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔
خطبۂ نکاح
اسلام سے پہلے بھی زمانۂ جاہلیت میں نکاح سے پہلے خطبے دئیے جاتے تھے لیکن وہ خطبے فخر وتعلّی اور نسبی تفاخر اور اپنے آباء واجداد کی مبالغہ آمیز مدح سرائی کا مجموعہ ہوتا تھا، اسلام جس کے نزدیک سوائے دین کے کوئی چیز وجہ تفاخر نہیں اور جو انسان سے زندگی کے ہر عمل میں تواضع وفروتنی اور عجز وانکسار کا طالب اور خدا کی حمدو ثنا اور اس سے دعا والتجا کا معلم ہے اس نے خطبۂ نکاح کو تو باقی رکھا لیکن اس کی کیفیت اور مضامین یکسر بدل کر رکھ دئیے اور اس کی جگہ ایسا خطبہ مقرر کیا جس میں خداکی حمدوثنا ہو،توحید و رسالت کا اعتراف و اقرار ہو، قرآن کی وہ آیات ہوں جن کا مقصد زندگی کے معاملات سے متعلق تنبیہ اور رہبری ہے،چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقعہ کے لئے جو خطبہ منقول ہے وہ یہ ہے:
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ
’’تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے،ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور ہم اپنے برے اعمال اور نفس کے شرور سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں، جسے خدارہ یاب کردے اس کوکوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جسے خدا گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور محمدﷺخدا کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ سے ڈرو جو اس کے ڈرنے کا حق ہے اورجان نہ دینا بجز اس کے کہ تم مسلم ہو، اللہ سے تقویٰ اختیار کرو جس کے واسطہ سے ایک دوسرے سے مانگتے ہواور قرابتوں کے باب میں بھی(تقویٰ اختیار کرو) بے شک اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے،وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی کامیاب و فلاح یاب ہے۔‘‘
اس کو عام طور پر حدیث میں’’خطبۃ الحاجۃ‘‘ یا’’ تشھد الحاجۃ‘‘ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے ، منشا یہ ہے کہ ہر ضرورت کے موقع پریہ خطبہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بیہقی کی ایک روایت میں نکاح کا صراحت سے ذکرموجود ہے’’اذااراد احدکم ان یخطب لحاجۃ من النکاح اوغیرہ الخ‘‘ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خصوصیت سے نکاح کے موقع پر یہ خطبہ دیاجاناچاہئے، سلف کا تبرکامذکورہ آیات کے بعد نکاح سے متعلق چند حدیثیں اور دعائیہ کلمات بھی پڑھے جانے کا معمول ہے۔
مستحبات و آداب
نکاح کے مستحبات و آداب میں سے یہ ہے کہ آپﷺ نے فرمایا ’’اعلنوا ھذا النکاح‘‘…یہ بھی مسنون ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے، ارشاد نبوی ہے:’’ واجعلوہ فی المساجد‘‘ یوں تو اسلام میں کوئی وقت منحوس نہیں لیکن چونکہ رسول اللہﷺ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح اور یکجوئی دونوں شوال کے مہینہ میں ہوئی اس لئے بعض اہل علم نے شوال میں نکاح کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ محرم، صفر، ذوالقعدہ کے مہینوں کو نکاح کے لئے منحوس اور نامناسب جانتے ہیں یہ قطعاً اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اسلامی تصورات کے مغائر ہے۔ اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح کے لئے بہتر اور مستحب دن جمعہ کا ہے۔
کھجور لٹانا
مجلس نکاح میں کھجور اور مصری وغیرہ کا لٹانا ہمارے علاقوں میں مروّج ہے اس میں توکوئی شبہ نہیں کہ فی نفسہٖ کھجور کا حاضرین کے درمیان لٹانا اور حاضرین کا لوٹنا حلال و مباح ہے اور اس پر اکل حرام کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن چونکہ اس لوٹنے میں باہم مزاحمت اور مخاصمت کی صورت پیدا ہوسکتی ہے ،اس لئے امام مالکؒ امام شافعیؒ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ اس کو منع کرتے ہیں، امام ابو حنیفہؒ اور بعض اہل علم کے نزدیک اس میں کوئی کراہت نہیں، امام احمدؒ کی بھی ایک روایت اسی کے مطابق ہے۔
جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کے پیش نظریہ ہے کہ رسول اللہﷺ نے پانچ یا چھ اونٹنیوں کا نحر فرمایا اور فرمایا کہ جو چاہے اس میں سے کاٹ لے۔’’من شاء اقتطع‘‘ یہ اجازت اور لٹائی ہوئی چیز میں سے لوٹنے کی اجازت بظاہر ایک ہی درجہ رکھتی ہے… بعض اہل علم نے اس کے جواز پر ایک انصاری کے واقعۂ نکاح سے استدلال کیا ہے جس میں خود رسول اللہﷺ نے میوے لٹائے تھے مگر واقعہ یہ ہے کہ اس روایت سے استدلال قرین انصاف نہیں کیونکہ اس میں بشر بن ابراہیم نامی راوی آیا ہے جس کے بارے میں محدثین کا خیال ہے کہ وہ حدیثیں وضع کیا کرتا تھا۔
تاہم اوپر جو باتیں مذکورہوئیں وہی اس کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں اور تجربہ یہ ہے کہ ایسی تقریبات میں مزاحمت اور مخاصمت اور باہم نزاع کی سی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، محض خوشی کا اظہار مقصود ہوتا ہے، فتاویٰ عالمگیری میں بھی اس موقعہ پر میٹھی چیزیادرہم وغیرہ لٹانے کا جواز نقل کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کہیں اس کی وجہ سے مجلس میں بدتہذیبی اور ناشائستگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو تقسیم کردینا بہتر ہے۔
مبارک باد
آپﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ نکاح کے بعد مبارک باد کے الفاظ کس طرح کہے جائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپﷺ نکاح کے بعد یوں مبارک باد دیتے:
’’بارک اللّٰہ وبارک علیک وجمع بینکمافی خیر‘‘
’’اللہ برکت دے تم پر برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے۔‘‘
حضرت عقیل بن ابی طالب کی روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں:
’’بارک اللّٰہ فیک و بارک لک فیھا‘‘
’’ اللہ تعالیٰ تمہاری ذات کو اور تمہارے لئے اس کی ذات کو مبارک کرے۔‘‘
٭…٭…٭
الفقہ
حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب ’’حلال وحرام‘‘ سے ماخوذ
(شمارہ 473)
دف وغیرہ
نکاح میں چونکہ اعلان اور اظہار مقصود ہے، اس لئے آپﷺ نے دف بجانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، ارشاد ہے:’’واضربواعلیہ بالدفوف‘‘ بلکہ عید کے موقعہ پر بھی آپﷺ نے کم عمر بچیوں کو دف بجانے سے منع نہیں فرمایا، بعد کو چل کرحالات زمانہ کو سامنے رکھتے ہوئے گودف جائزہونے اور نہ ہونے میں اہل علم کی آراء مختلف ہوگئیں لیکن زیادہ ترفقہاء کا رحجان اس کے جائز ہونے کی طرف ہے، یہی امام ابو یوسفؒ سے منقول ہے اور اسی طرح کی بات حنابلہ وغیرہ نے لکھی ہے لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ گانا بجانا، مزامیر کا استعمال ، تالیاں، طبلے، عورتوں کا برسرمحفل پڑھنا، یہ قبیح رسمیں جو ہمارے یہاں رائج ہوگئی ہیں، قطعاًنا جائز اور حرام ہیں اور فی زمانہ ان غیر شرعی رسوم کے سد باب کے لئے دف کو بھی ممنوع قرار دینا ضروری ہے۔
دلہن کو رخصت کرنا
نکاح کے بعد عورتوں کا لڑکی سنوارنا اور شوہر کے ہاں پہنچانا یارخصت کرنا جس کو ’’زفاف‘‘ کہا جاتا ہے ، جائزہے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں اس کا ذکرموجود ہے اور فقہاء نے بھی اس کو جائزقرار دیا ہے بشرطیکہ کوئی مفسدئہ دینی نہ ہو…لیکن عورتوں کا ایسا اجتماع جس میں بے پردگی اور خلاف شریعت باتوں کا ارتکاب ہوتا ہو چونکہ دینی مفسدہ سے خالی نہیں ، اس لئے جائز نہ ہوگا۔
ولیمہ
نکا ح چونکہ ایک تقاضۂ انسانی کی تکمیل کا حلال وجائز ذریعہ ہے، اس لئے شریعت نے اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر و اظہار کو پسند کیا ہے، اسی تشہیر اور اظہار کا ایک طریقہ ولیمہ بھی ہے جس میں دعوت عام کے ذریعہ مردوزن کے درمیان تعلق ازدواجی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپﷺ نے خود ولیمے کئے ہیں اور صحابہؓ کو بھی اس کی ترغیب دی ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تو آپﷺ نے ان سے بھی ولیمہ کے لئے تاکید فرمائی اور فرمایا: ’’اولم ولوبشاۃ‘‘ لہٰذاولیمہ رسول اللہﷺ کی خاص سنتوں میں سے ہے۔
ولیمہ میں کس طرح کے کھانے بنائے جائیں؟ یہ دعوت ولیمہ دینے والے کی معاشی سطح پر موقوف ہے،چنانچہ خود حضورﷺ نے جہاں حضرت زینبؓ کے نکاح میں بکری ذبح کر کے ولیمہ فرمایا، وہیں بعض ازواج مطہراتؓ کا ولیمہ محض تھوڑی سی جوکے ذریعہ فرمایا ہے’’ بمدین من شعیر‘‘ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ کا تعلق آدمی کی معاشی حیثیت اور سطح سے ہے۔ ولیمہ میں بہت زیادہ تکلفات اور حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں۔
ولیمہ بیوی کے ساتھ تعلق ازدواجی کے بعد ہونا چاہئے۔ ایک روایت میں صراحت کے ساتھ موجودہے کہ جب آپﷺ کی حضرت زینبؓ کے ساتھ شب عروسی ہوگئی تب آپﷺنے قوم کو بلایا اور ان حضرات نے کھانا تناول فرمایا۔
حدیثوں میں دعوت ولیمہ قبول کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، ابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی کو دعوت دلیمہ دی جائے تو اسے ضرور آناچاہئے۔
بعض روایات میں دعوت ولیمہ قبول نہ کرنے کو نافرمانی اور معصیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علامہ ابن عبدالبرؒ نے امام مالکؒ ،امام ابو حنیفہؒ، اما م شافعیؒ وغیرہ سے دعوت ولیمہ کے قبول کرنے کا واجب ہونا نقل کیا ہے، بشرطیکہ متعین طور پر کسی شخص کو دعوت دی جائے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس دعوت کا قبول کرنا بھی مسنون ہے البتہ شریعت میں اس کی بڑی تاکیدواہتمام ہے’’وقالت العامۃ ھی السنۃ‘‘
غیر مسلم دعوت دے اور اپنے یہاں تقریب نکاح میں بلائے تو اس میں بھی شرکت جائز ہے۔ اگر دعوت ولیمہ میں منکرات شرعیہ کاارتکاب ہو تو اس میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ اس سلسلہ میں اصول وہی ہیں جو عام دعوتوں کے سلسلہ میں ہیں اور ان کا ذکر پہلے ہوچکا ہے۔
رسول اللہﷺ نے اگلے دن ولیمہ کو حق ،دوسرے دن درست اور تیسرے دن ریاکاری قراردیا ہے۔ اس لئے مسلسل دوتین دنوں تک یا اس سے زیادہ ولیمہ کا اہتمام اوردعوت کا سلسلہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اگر تفاخر کا جذبہ نہ ہو، لوگ زیادہ ہوں اور ایک آدمی ایک ہی بارشریک طعام ہو، دوسرے اور تیسرے دن کے مدعوئین الگ ہوں تو ایک سے زیادہ دن بھی ولیمہ کا اہتمام جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق آپﷺ نے حضرت صفیہؓ سے نکاح کے موقعہ پر تین دنوں تک ولیمہ فرمایا ہے۔ بلکہ حفصہ بن سیرین ناقل ہیں کہ ان کے والد نے تو سات دنوں تک ان کا ولیمہ کیا اور مختلف صحابہ کو مختلف دنوں میں دعوت دی۔ ہمارے فقہاء نے عام طور پر یکجائی کے بعد اس دن یا دوسرے دن دعوت ولیمہ منعقد کرنے کو کہا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے بعد ولیمہ نہیں ہوگا۔
مہر
نکاح کی وجہ سے عصمت انسانی کے احترام کے اظہار کے لئے شریعت نے شوہر پر بیوی کا ایک خاص مالی حق رکھا ہے جس کو مہر کہا جاتا ہے ،حدیث میں بعض مواقع پر’’صداق‘‘ یاکسی اور نام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے ،ارشاد خداوندی ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کردئیے جائیں۔’’ وَاٰتُواالنِّسَآئَ صَدُقٰتِھِنَّ نِحْلَۃً‘‘ بلکہ اسی مہر کے ذریعہ ایک خاص معاہدہ کے تحت عورت کی عصمت مرد کے لئے حلال ہوتی ہے۔’’ واحل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم‘‘ مرد کو عورت پر ازدواجی زندگی میں جو ایک گونہ بالا دستی حاصل ہے، اس کی وجہ جہاں مرد کی بعض فطری خصوصیات ہیں وہیں یہ بھی ہے کہ مہر اور دوسری مالی ذمہ داریاں مردوں کے سررکھی گئی ہیں۔
مہر کی مقدار
قرآن مجید نے اس بات کی تو صراحت کردی ہے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار متعین نہیں۔ حضر ت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ نے ایک خاتون سے نکاح کیا تو اسے سوباندیاں بھیجیں اور ہر باندی کے ساتھ ایک ہزار درہم۔مہر کی کم سے کم مقدار کے سلسلہ میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں، بعض فقہاء کے نزدیک کم سے کم کوئی مقدار نہیں۔بعضوں کا خیال ہے کہ کم سے کم مہر کی مقدار ۴/۱دینار(تقریباًساڑھے چار ماشہ سونا) ہونا چاہئے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے۔ ۲ تولہساڑھے سات ماشہ چاندی کے مساوی ہوتا ہے… ان تمام ہی فقہاء کے پاس اپنی آراء کے لئے مناسب دلیلیں موجود ہیں۔ احناف کے پیش نظر وہ روایت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مہر دس درہم سے کم نہ ہوناچاہئے۔’’ لامھر اقل من عشرۃ دراھم‘‘
مہر کی تعیین میں اعتدال ہونا چاہئے، نہ مہر اتنا معمولی ہو کہ اس کی کوئی قدر باقی نہ رہے۔ نہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کی ادائیگی دشوار ہوجائے اور مرد کی معاشی حالت اس کی متحمل نہ ہو، سیدنا حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کی کثرت میں غلو کو بہت ناپسندفرمایا ہے اور فرمایا کہ مہر کی کثرت اگر فخروشرافت کی بات ہوتی تو ازواج مطہرات کا مہر زیادہ ہوتا۔ ازواج مطہرات کا مہر بالعموم پانچ سوردرہم تھااور صاحبزادیٔ رسولﷺسیدہ فاطمہؓ کا مہر چار سواسی درہم۔
(جاری ہے)